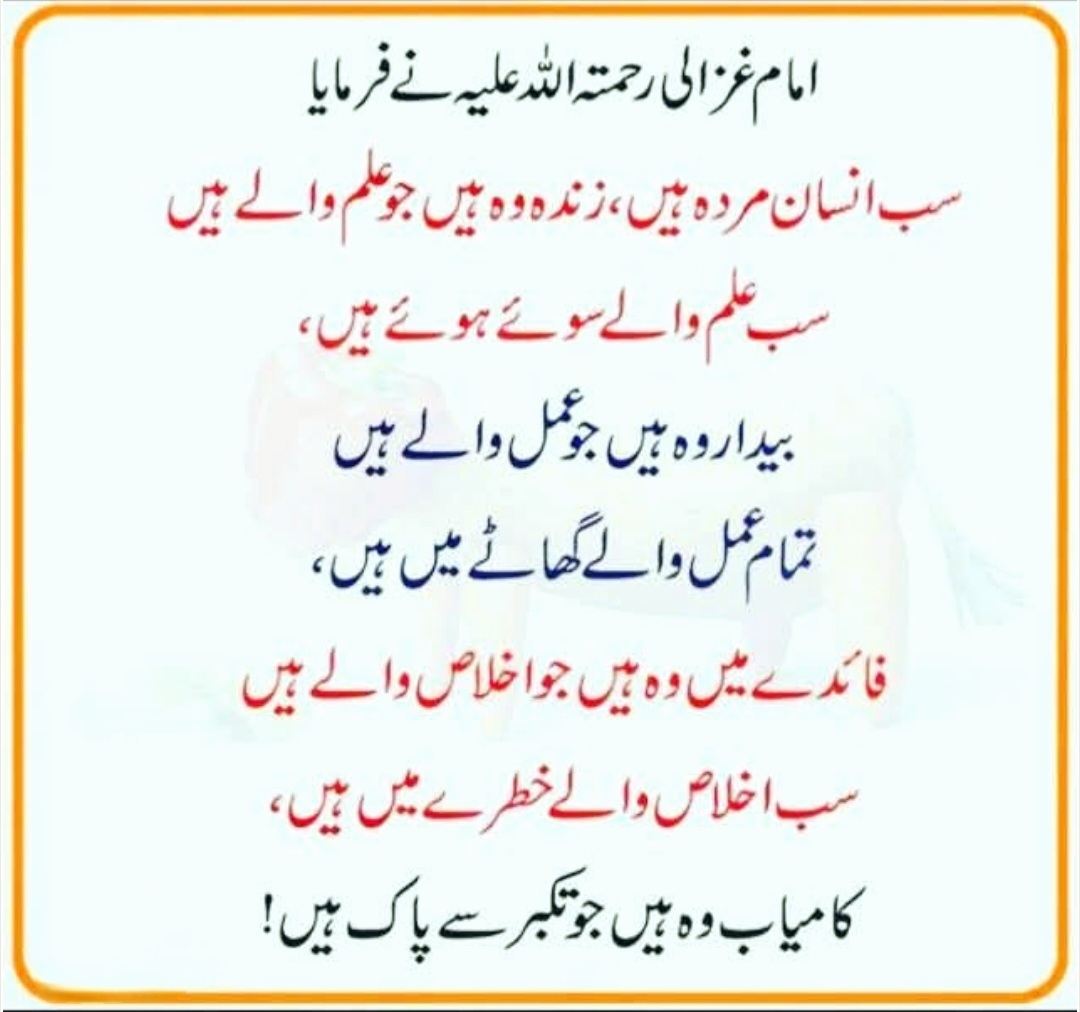Friday, 31 January 2025
اسلامی معاشرہ کا ایک بھولا سبق
Thursday, 30 January 2025
محبت کا معیار
محبت کا معیار
مرد کو اپنی بیوی سے اور عورت کو اپنے شوہر سے کتنی محبت ہونی چاہئے- الله تعالی نے انسان کو انسانی صفات، عادات و اخلاق پر ڈھالا ہے۔ جس کو جبلت و فطرت بھی کہتے ہیں، جس پر انسان کو ڈھالا جائے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، کہاوت ہے:
"جبل گردد جبلت نگردد"
ان صفات و عادات میں سے ایک "محبت" ہے۔ الله تعالی نے محبت کرنے کا جذبہ، صلاحیت، استعداد ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ وہ اپنے دل کا کھچاؤ ضرور کسی کی طرف محسوس کرتا ہے۔
محبت گناہ نہیں:
اور محبت کرنا گناہ نہیں ہیں، ہاں اسباب گناہ ہوسکتے ہیں۔ طور طریق گناہ ہوسکتا ہے لیکن کسی پر دل آجانا برا نہیں، کسی کے حسن و جمال، کمال و منال پر فریفتہ ہونا گناہ نہیں۔ "ولو اعجبک حسنھن" ہم نے اپنے بڑوں سے یہ شعر سنا ہے:
گر سمجھو تو ایک بات کہوں
عشق توفیق ہے گناہ نہیں
محبت میں انسان مجبور ہے
پھر محبت اضطراری ہے کہ یہ تو دل کا کام ہے،
"بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے"
اور دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کسی پر مر مٹتا ہے، کسی پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، دل کا سودا کرکے سودائی ہوجاتا ہے۔ اس سودائی سے کوئی پوچھے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو؟ کس پیچ و تاب میں ہو ؟تو جواب اس کا یہی ہوتا ہے:
محبت ہو تو جاتی ہے محبت کی نہیں جاتی
یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے بھڑکا یا نہیں جاتا
محبت کسے کہتے ہیں:
بعض چیزیں دقیق و غامض ہوتی ہی اس لیے ان کی تعریف دشوار ہوجاتی ہیں، بعض چیری عیاں، روشن واضح ترین بلکہ ابدہ البدیہیات ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کی تعریف دشوار ہوجاتی ہے۔ علم کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے۔ حتی کہ بعضوں نے تو اسے ناقابل تعریف قرار دے دیا۔ محبت بھی اسی قسم میں سے ہے۔ کسی نے کہا:
"میل القلب الی الشیئ لتصور کمال فیہ" [العینی]
یعنی دل کا کسی چیز پر آجانا اس کے اندر موجود کسی کمال کی وجہ سے۔
المیل الی مایوافق المحب [النووی]
محبوب کے موافق و پسندیدہ چیز کی طرف میلان کا نام محبت ہے، کسی نے کہا: بھلی، خوشگوار لگنے والی چیز کی طرف دل کا جھکاؤ۔ کسی نے کہا: محض محبوب کی خواہش کے پیش نظر اپنی خواہش کو پیروں تلے روند دینا۔ تقی صاحب فرماتے ہیں:
محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہوجانا
متاعِ جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہوجانا
کسی نے کچھ کہا ہے اور کسی نے کچھ۔ اس مقام کے مناسب، سپر ڈال دینا ہے، یہ ایک بدیہی چیز ہے، جیسے انسان پیٹ میں بھوک محسوس کرتا ہے، وہ اپنے دل میں محبت بھی محسوس کرتا ہے اس کو تعریف کرکے سمجھایا نہیں جاسکتا۔ بقول شاعر:
محبت اصل میں "مخمورؔ" وہ رازِ حقیقت ہے
سمجھ میں آگیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا
محبت کی کئی قسمیں کی گئی ہیں؛ لغوی عرفی اختیاری اضطراری عشقی ایمانی، حقیقی مجازی ہوسکتا ہے تعریف میں اس اعتبار سے فرق ہو، یا ہوسکتا ہے ابتداءو انتہاء کا فرق ہو،
ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا
آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا
جیسے انتہاء پر پہچنے کے بعد کوئی عاشق کہہ اٹھتا ہے " بخدا میرا سر قلم ہونے سے بچ جائے اور حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں"
کسی شاعر نے کہا ہے:
من تو شُدم تو من شُدی، من تن شُدم تو جاں شُدی
تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری [امیر خسرو دہلوی]
میں تُو بن گیا ہوں اور تُو میں بن گیا ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے۔ پس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ نبی کی چاہت میں یہی مطلوب ہے کہ انسان ہر چیز/ ہر شخص کی محبت پر نبی کی محبت کو بڑھا دے والد اور اولاد کی محبت سے بھی حتی کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ نبی کی محبت ہو۔ [بخآری]
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے عاشقان رسول نے ایسا کرکے بتایا وہ ایک جان دو قالب تھے، ان کی وہی خواہشات، جذبات و پسند نا پسند تھیں جو نبی کی تھی۔
أَنا مَن أَهوى وَمَن أَهوى أَنا
نَحنُ روحانِ حَلَنا بَدَنا
میاں بیوی کی محبت:
آج کل جب محبت، پیار، عشق بولا جاتا ہے تو عورت کی مرد سے اور مرد کی عورت سے عشق ہی مراد لیا جاتا ہے، معاشرے میں اسے بہت بڑا درجہ دے دیا گیا ہے جو نہ سرحدیں دیکھتا ہے نہ حدیں، نہ رنگ و نسل دیکھتا ہے نہ تہذیب و کلچر، نہ دھرم دیکھتا ہے نہ مذہب، کہا جاتا ہے محبت اور پیار سب سے اوپر ہے، پیار اندھا ہوتا ہے، محبت کا کوئی مذہب نہیں یہ مذہب سے بالاتر ہے. [العیاذ بالله]
حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو فرمایا تھا والدین سے ["والد" بمعنی من له الولد]، اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ "زوجہ" کا ذکر صراحتا نہیں کیا بلکہ اسے "والناس اجمعین" کے ضمن میں بیان کیا۔ اور سورۂ توبہ میں الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں (اے رسول !) آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا۔ تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، مال و اسباب جن کو تم نے حاصل کیا ہے، (تمہاری) تجارت جس کے بیٹھ جانے کا تمہیں ڈر لگارہتا ہے اور وہ رہائش گاہیں جنھیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ جاری کردیں، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس فرمان میں بھی بیوی کی محبت کو باپ دادا، اولاد اور بھائیوں کے بعد رکھا ہے۔ میرا مقصود بیوی سے محبت کی نفی نہیں ہے بس درجات کا تعین ہے، آخر زمانے میں لوگ بیوی کی محبت میں بیوی کو ماں سے زیادہ ترجیح دینے لگے گیں، مقصد اس کی روک تھام ہے، غلو سے اور اس سلسلے میں ہونے والی خطاووں سے محافظت ہے۔ فی نفسہ میاں بیوی کی محبت تو ان کی فطرت اور گٹھی میں ہے، الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے جوڑے (بیویاں) بنادیئے؛ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان پائیدار محبت اور ہمدردی پیدا کردی. [سورۂ روم: ۲۰]
الله تعالی نے انسانوں کے فائدے کے لیے بیویاں بنائی، سوچو اگر اس دنیا میں صرف مرد ہی مرد ہوتے عورتوں کا نام و نشان نہ ہوتا تو دنیا کتنی بے رونق ہوتی، دنیا کی سرسبز و شادابی اور خوش نمائی بے رنگ ہوجاتی، زندگی بدمزہ بے ڈھنگ ہوتی۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ مرد عورت کے پاس جاکر بیٹھے اس سے باتیں کرے اس سے لذت حاصل کرے اور سکون پائے، سکون پانے کے لیے آسانی ہو اس لیے ان دونوں میں پائیدار محبت اور ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ و میلان رکھا اور شفقت و ہمدردی بھی۔ اگر محبت نہ ہو تو آدمی اس سے بچے ہونے کی وجہ سے یا اس کی ضرورت ہونے کی وجہ یا اس کے ساتھ کافی عرصہ ساتھ گزارنے کی وجہ سے اس سے مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمدردی بھی رکھی گئی۔ یہ محبت میاں بیوی کی عموما "نکاح" سے وجود میں آتی ہے، الله تعالی نے نکاح کو بنایا ہی ایسی چیز ہے کہ ایک لفظ ہی سے دو پرائے اشخاص ایک دوسرے کے لیے شیر وشکر ہوجاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:
"لم تر للمتحابين مثل النكاح۔"
"تم دو محبت کرنے والوں کے لئے نکاح کی طرح کوئی چیز نہیں پاؤگے۔" مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ جس طرح خاوند اور بیوی کے درمیان بغیر کسی قرابت کے بے پناہ محبت والفت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کا کوئی تعلق ایسا نہیں ہے جو دو شخصوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لئے بالکل اجنبی ہوں، اس درجہ کی محبت والفت پیدا کردے۔ یا مطلب یہ ہے کہ مرد کسی پر فریفتہ ہوگیا تو اس فریفتگی اور محبت کا بقا نکاح سے بہتر کسی چیز میں نہیں۔ رسول اللہ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین مشعلِ راہ ہے، آں حضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنی ازواجِ مطہرات اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہایت محبت رکھتے تھے اور یہ تمام صحابہ کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصدًا اسی روز ہدیے اور تحفے بھیجتے تھے جس روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کی باری ہوتی۔ [بخآری]
اسی محبت کی وجہ سے آپ اپنے زندگی کے ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنھا کے پاس گزارنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے آپ ان کی عزت افزائی کرتے اور کبھی "یاموفقہ" فرماتے کبھی فرماتے "جس طرح ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے اسی طرح عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے [شمائل ترمذی] کبھی فرماتے:
"أنا لك كأبي زرع لأم زرع"
میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے۔ کبھی بیوی کی محبت یا شوہر کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے جو اس کے لیے دینی یا دنیاوی ذمہ داریوں میں مخل ہوتی ہے یا مضر ہوتی ہے ایسی محبت نہیں ہونے چاہیے، کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے یا یہ محبت سے برے یا غلط کام پر آمادہ کرے۔ ایسی خبریں بسا اوقات کانوں سے ٹکراتی ہیں کہ کسی مرد/عورت کو اس کے محبوب نے چھوڑ دیا تو وہ دماغی مریض ہوگیا یا نشےکی لت اختیار کرلی یا کام کاج سے بیٹھ کر دین و دنیا سے بے گانا ہوگیا یا خود کشی کرلی بلکہ بعض ناسمجھ بچیوں کادین تک چھوڑنے کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ کسی کی محبت کو اتنا غالب نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ اپنا یا اپنے دین کا ہی نقصان کر بیٹھے۔ ہمارے اکابر اگر یہ دیکھتے کہ وہ بیوی کی محبت کی وجہ سے دینی کاموں میں عبادت و ریاضت میں کوتاہی کررہا ہے تو اسے طلاق دینے کا حکم دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، نہایت حکیم اور مدبر شخص تھے جب انھوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا عبدالله (رضی الله تعالی عنہ) نکاح کے بعد اپنی بیوی سے اس قدر لگاؤ کر رکھا ہے کہ عبادت و مجاہدت میں مخل ہوگا تو انھوں نے طلاق دینے کا حکم دیا- حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ بھی پریشان کہ کیا کریں۔ انھوں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے الله کے رسول! ابا تو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں؟ کیا کروں؟ تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے ابا کا کہا مانو۔ پھر جب دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ طلاق دینے کہا تو فورا طلاق دے دی، بعد میں بیٹے نے کہا کہ وہ تو فی الحال حائضہ ہے (میں نے اس لیے پہلے نہیں کہا کہ کہیں آپ اسے طلاق نہ دینے کا بہانا نہ سمجھ لیں) ابا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفسار کیا، آپ نے رجوع کرکے پھر ایسے طہر میں طلاق دینے کہا جس میں بیٹے نے بہو سے ہم بستری نہ کی ہو، اور چاہو تو نکاح میں روک بھی سکتے ہو، آپ نے اختیار بھی دیا۔ بہرحال انھوں نے رجوع کیا پھر طلاق نہیں دی کیوں کہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب پہلے جیسی شدید محبت باقی نہیں رہی تھی۔
مطالبہ حقوق کا ہے محبت کا نہیں:
جیسا کہ آپ حضرات جان چکے ہیں، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا- دل بے قابو ہیں، محبت غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مردوں سے بھی مطالبہ ادایئگئ حقوق کا ہے اور عورتوں سے بھی، آپ قرآن و حدیث پڑھو گے اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بیوی سے محبت کرو، محبت پر دائم رہو یا محبت بڑھاؤ بلکہ دونوں کو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی مرد کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کے بنا جینا ادھورا ہے، زندگی فضول ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے اور حقوق ادا نہیں کرتا نہ اخراجات پورے دیتا ہے نہ خبر گیری کرتا ہے تو یہ زبانی جمع خرچی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یہ کہے آپ میرے سرتاج ہو جان ہی نہیں جان جہاں ہو، تمہارے بنا میں جی تو کجا مر بھی نہیں سکتی، میرے رگ و ریشہ تمہاری محبت میں سرشار ہے لیکن شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی نہ اطاعت کرتی ہے نہ تعظیم تو یہ صرف زبانی ڈھکوسلے اور دغا بازی ہے۔ شاعر کہتا ہے:
لو كان حبك صادقـاً لأطعتـه
إن المحب لمن يحب مطيـع
اگر تو محبت میں سچی ہوتی تو میری اطاعت کرتی، اس لئے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔
(محمد یحیی بن عبدالحفیظ)
https://saagartimes.blogspot.com/2025/01/blog-post_30.html
Monday, 27 January 2025
بدن سے نکلنے والے خون کے ناقض وضوء ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں ائمہ کرام کے نقطہاے نظر
Sunday, 26 January 2025
اسقاط حمل کیوں ممنوع ہے؟
Monday, 20 January 2025
مخارج حروف
Monday, 13 January 2025
لائے ہیں دل کے داغ نمایاں کئے ہوئے
Friday, 10 January 2025
حضرت الاستاذ علامہ قمرالدین احمد صاحب گورکھپوری رحمہ اللہ: یادوں کے نقوش
Tuesday, 7 January 2025
کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت اور مذاہبِ ائمہ
کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت اور مذاہبِ ائمہ
----------------------------------
----------------------------------
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "اللہ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نظرِ رحمت نہیں کرے گا، جو تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پر لٹکائے۔" (صحیح بخاری: 5788)
حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت:
مَن جَرَّ ثوبَه خُيَلاءَ، لم يَنظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ —-“جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ لٹکائے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔”أخرَجَه البُخاريُّ (3665) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2085).
اور حضرت جابر بن سُلَیم کی روایت:
إيَّاكَ وإسبال الإزارِ؛ فإنَّها مِن المَخِيلةِ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المَخِيلةَ —-"ازار (کپڑا) لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر میں شامل ہے، اور بے شک اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔" (أخرجه أبو داود (4084)، والبيهقي (21623)
اور ان جیسی دیگر احادیث کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیدیا گیا ہے، حرمت کی وجہ تکبر اور گھمنڈ ہے۔ اس علت وحکمت کے ساتھ اسبال ازار کی حرمت پہ ائمہ اربعہ متفق ہیں (دیکھئے الفتاوى الهندية: 5/333)، مواهب الجليل للحَطَّاب :1/220)، المجموع للنووي :4/454) كشَّاف القِناع للبُهُوتي 1/277).
لیکن اگر اسبال ازار بغیر غرور وتکبر کے کسی عارض کے باعث ہو تو کیا یہ صورت بھی حرمت میں داخل ہے یا اس کی گنجائش ہے؟ تو حنابلہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں اس مسئلے میں کراہت کا قول منقول ہے، فقہاء حنابلہ، ابن العربي، امام ذهبي، اور علامہ ابن حجر عسقلانی وغیرھم کا رجحان اب بھی حرمت ہی کا ہے.
(وفي هذه الأحاديثِ أنَّ إسبالَ الإزارِ للخُيَلاءِ كَبيرةٌ، وأمَّا الإسبالُ لغَيرِ الخُيَلاءِ، فظاهرُ الأحاديثِ تَحريُمه). (فتح الباري (10/263).
یعنی ان کے یہاں اسبال ازار مطلقاً حرام ہے، خواہ بقصدِ تکبر ہو یا نہ ہو۔ اِن حضرات کے پیش نظر وہ روایات ہیں جن میں تکبر کی قید کے بغیر مطلقاً ممانعت وارد ہوئی ہے:
۱: عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (ما أسفَلَ مِن الكَعبينِ مِن الإزارِ، ففي النَّارِ—- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ازار (کپڑے) کا ہوگا، وہ آگ میں ہوگا۔” (أخرَجَه البُخاريُّ (5787).
۲: عن أبي ذَرٍّ الغِفارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ ولا يَنظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ، قال: فقرأها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثَ مَرَّاتٍ. قال أبو ذَرٍّ: خابوا وخَسِروا، من هم يا رسولَ اللهِ؟ قال: المُسبِلُ، والمَنَّانُ، والمُنَفِّقُ سِلعَتَه بالحَلِفِ الكاذِبِ— حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔" آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: "وہ لوگ برباد اور خسارے میں ہیں، یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ شخص جو اپنا کپڑا لٹکائے، وہ شخص جو کسی پر احسان جتائے، اور وہ شخص جو اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے۔" (أخرجه مُسْلِم (106) جبکہ ائمہ ثلاثہ میں شوافع وحنابلہ وجمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ مطلق روایات کو مقید روایات پر محمول کیا جائے گا، اور بقصد عجب وغرور ٹخنہ سے نیچے إسبال ازار ہو تو ممنوع ہوگا ؛ ورنہ مکروہ تنزیہی ہوگا ۔ گوکہ بہتر (پہلا درجہ) یہی ہے کہ ازار نصفِ ساق (ٹخنہ اور گھٹنہ کے درمیان کی لمبی ہڈی کو ساق کہتے ہیں) تک رہے، آدھی پنڈلی سے ٹخنے تک کے درمیان والے حصے تک بھی کوئی مضائقہ نہیں؛ یعنی جائز ہے (یہ دوسرا درجہ ہے)؛ لیکن ٹخنہ سے نیچے جو حصہ غرور وتکبر کی بنا پر لٹکا ہوا ہوگا وہ بہر صورت دوزخ میں لے جانے والا اور گناہ کبیرہ ہوگا؛ لیکن اگر طہارت ونظافت کے ساتھ ٹخنہ سے نیچے بھی کسی باعث بغیر کبر وغرور کے ہوجائے تو یہ حرام وممنوع نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ تنزیہی ہے (یہ تیسرا درجہ ہے)، حرام صرف غرور وتکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی درج ہے۔ ان کا مستدل ابن عمر کی حدیث بخاری (5783) ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اجازت مرحمت فرمائی تھی (لست ممن يصنعه خيلاء):
۱: عن سالم عن ابن عمر "مَن جرَّ ثَوبَهُ خُيلاءَ لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ يَومَ القيامةِ قالَ أبوبكرٍ: إنَّ أحدَ جانبَي إزاري يستَرخي، [إلَّا] إنِّي لأتعاهدُ ذلِكَ منهُ، قالَ: لستَ ممَّن يفعلُهُ خُيلاءَ (مسند احمد 5920) حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ ﴿حضرت عبداللہ بن عمر﴾ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور کی بنا پر کپڑا زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: "اے اللہ کے رسول! کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے تہبند کا ایک حصہ لٹکتا رہتا ہے مگر میں اسے درست کرلیتا ہوں۔" اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تمھارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو غرور کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔"
۲: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، وَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا" (بخاری 5785)
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: "ایک مرتبہ سورج گہن ہوا، اور ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس موجود تھے۔ آپ ﷺ جلدی میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے اٹھے یہاں تک کہ مسجد پہنچے۔ لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہولیے۔ پھر آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی، اور گہن دور ہوگیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب تم ان میں سے کسی چیز کو (گہن وغیرہ) دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ گہن ختم ہوجائے۔"
۳: عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (إِزْرةُ المُسلِمِ إلى نِصفِ السَّاقِ، ولا حَرَجَ- أو لا جُناحَ- فيما بينه وبين الكَعبَينِ، ما كان أسفَلَ مِن الكَعبَينِ فهو في النَّارِ، مَن جَرَّ إزارَه بطَرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه —-"مسلمان کا لباس نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور ٹخنوں تک ہونے میں کوئی حرج یا گناہ نہیں۔ لیکن جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ آگ میں ہوگا۔ اور جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ گھسیٹے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں کرے گا۔" (أخرجه أبو داود (4093) واللَّفظُ له، والنَّسائي في (السنن الكبرى) (9717)، وابنُ ماجه (3573)، وأحمد (11397)
۴: عن عبدالله بن مسعود أنه كان يُسبل إزاره ، فقيل له في ذلك فقال إني رجل حمش الساقين. (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنا ازار (کپڑا) ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے۔ کسی نے ان سے اس بارے میں کہا تو انہوں نے جواب دیا: "میں کمزور پنڈلیوں والا آدمی ہوں۔") [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/27) طبعة دار الفكر ، وصححه ابن حجر في فتح الباري (10/264) طبعة دارالفكر] ان حضرات کا کہنا ہے کہ ان روایات میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے پر وعید ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو یہ کام تکبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اگر کوئی بغیر تکبر کے کپڑا لٹکائے تو یہ حرام نہیں ہوگا، ہاں مکروہ تنزیہی ضرور ہوگا۔ فتاوی ہندیہ میں ہے: إسْبَالُ الرَّجُلِ إزَارَهُ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْخُيَلَاءِ فَفِيهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، كَذَا فِي الْغَرَائِبِ. (الفتاوی الهندية ٣٣٣/٥) وحاشية البخاري للسهارنفوري رقم الحديث 3665)
البحرالرائق میں ہے: وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ السَّرَاوِيلُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ( البحرالرائق ٢١٦/٨)
بذل المجهود میں ہے: من حديث حذيفة بلفظ "الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار"، انتهى.
وهذا صريح في أنه لا يجوز ستر الكعبين، وقال ابن عابدين في الكلام على آداب اللبس وأحكامه (٩/ ٥٠٦): ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين، "عتابية"، انتهى. وهكذا في البحر (٢١٦/٨)
وقال النووي في "شرح مسلم ٣١٣/٧): فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه، انتهى الأبواب والتراجم ١٦٨/٦)
قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلَّا فمنع تنزيه. (بذل المجهود ١١٣/١٢…رقم الحديث 4085)
المنتقى شرح الموطأ (7/226)
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) (2/453)، مغني المحتاج) للشربيني (1/309)، (نهاية المحتاج) للرملي (2/382)، (شرح النووي على مُسْلِم) (14/62) المغني (2/298)
علامہ نووی صحیح مسلم ج۷، صفحہ ۳۱۳ میں فرماتے ہیں: ’’وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء، لأنه مطلق ، فوجب حمله على المقيد—اورجن احادیث میں مطلقاً آیا ہے کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو تکبر کی وجہ سے لٹکایا گیا ہو۔ کیوں کہ یہ احادیث مطلق ہیں اور مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے.‘‘
حافظِ ثانی علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ قیدِ خیلاء ممانعت وحرمت کی وجہ وعلت (مناط حکم) نہیں ہے، یہ قید واقعی ہے، اُس وقت عرب کے لوگ عجب وغرور کے لئے ہی إسبال ازار کرتے تھے، إسبال ازار کا فعل ہی تکبر کو مستلزم ہے، اب الگ سے اس میں نیت یا قصد تکبر کو نہیں ڈھونڈا جائے گا، حضرت جابر کی روایت "وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ" (ابودائود ٤٠٨٤)– اسبالِ ازار سے بچو! کیوں کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے) سے اس کی تائید ہوتی ہے؛ لہذا عجب وغرور ہو یا نہ ہو بہر دو صورت یہ ممنوع وناجائز ہوگا، ہاں جب بلا قصد وعمد ایسا ہوجائے تو معفوعنہ ہے، لیکن باضابطہ قصد وعمد کے ساتھ لمبا ازار پہننا اور اس کی عادت ڈالنا، اس فیشن کو رواج دینا سخت وعید نبوی کے پیش نظر بالکل جائز نہیں ہے: علامہ کشمیری فرماتے ہیں: "وجرُّ الثوب ممنوعٌ عندنا مطلقًا، فهو إذن من أحكام اللباس، وقصرَ الشافعيةُ النهي على قيد المخيلة—" "ہمارے نزدیک ٹخنہ سے نیچے کپڑا لٹکانا مطلقاً ممنوع ہے، لہٰذا یہ لباس کے احکام میں سے ہے۔ جبکہ شافعیہ نے اس ممانعت کو تکبر (یعنی مخیلہ) کی قید کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔" (فیض الباری ٧٢/٦) رقم الحديث 5783، الأبواب والتراجم (١٦٥/٦)
جہاں تک عمومی وعید والی روایات کو قیدِ خیلاء پر محمول کرنے والے استدلال کی بات ہے تو حنفیہ کے یہاں تو مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی تو ویسے ہی گنجائش نہیں ہے کہ یہ لغت کے خلاف ہے (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] رقبہ مطلقہ اور رقبہ مومنہ کے ذیل میں اس کی تفصیلات موجود ہیں) شوافع وغیرہ کے یہاں ایسا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب مطلق ومقید روایت کا حکم وسبب ایک ہو، اگر حکم اور سبب مختلف ہوں تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جاسکتا، یہاں سبب اور حکم کا اختلاف واضح ہے:
1. حکم کا اختلاف:
• حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وعید یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کی طرف نظر نہیں کرے گا. (لم ينظر الله إليه يوم القيامة)
جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وعید یہ ہے کہ ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا. (ما أسفَلَ مِن الكَعبينِ مِن الإزارِ، ففي النَّارِ)۔
2. سبب کا اختلاف:
• حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وعید کا سبب تکبر(من جر ثوبه خيلاء) ہے۔
• جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وعید کا سبب ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا (ما أسفَلَ مِن الكَعبينِ) ہے۔
لہذا، درست بات یہ ہے کہ اب مطلق روایت کو مقید صورت پر محمول نہیں کیا جاسکتا، اور ٹخنہ سے نیچے کپڑا لٹکانے کی یہ وعید دونوں صورتوں پر لاگو ہوتی ہے، چاہے کپڑا تکبر کے ساتھ لٹکایا جائے یا بغیر تکبر کے۔
علاوہ ازیں جیساکہ ہم نے شروع میں عرض کیا احکام شرع کے متعدد اغراض ومقاصد وحِکَم ہوتے ہیں، یہاں بھی صرف تنہا عجب وغرور ہی وجہِ ممانعت نہیں ہے ؛ بلکہ اس کے ساتھ کپڑا لٹکانے میں اور بھی کئی خرابیاں موجود ہیں:
1. عورتوں سے مشابہت:
کپڑا لٹکانے میں عورتوں سے مشابہت ہے، کیونکہ انہیں اپنے لباس کو زمین تک لٹکانے کا حکم دیا گیا ہے۔
دلیل: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
"اللہ نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی طرح لباس پہنے۔" (مسند احمد 8425)
2. نجاست کے لگنے کا خدشہ:
لباس لٹکانے سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ نجاست اس سے لگ سکتی ہے۔
دلیل: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے وقت، انہوں نے اس نوجوان سے کہا جو ان کے پاس آیا تھا: "اپنا کپڑا اوپر کرو، یہ تمہارے لباس کے لیے زیادہ صاف اور تمہارے رب کے لیے زیادہ متقی ہے۔" (صحیح ابن حبان 6918)
3. تکبر کا امکان:
لباس لٹکانا تکبر کے اظہار کا امکان رکھتا ہے۔
ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے کرے اور کہے کہ میں اسے تکبر کے بغیر لٹکاتا ہوں، کیونکہ ممانعت کا حکم اس لٹکانے کو شامل ہے۔ اور جس شخص کا عمل اس ممانعت کو شامل ہو، اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں اس ممانعت کا مرتکب نہیں ہوں کیونکہ مجھ میں تکبر نہیں۔ یہ دعویٰ ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ لباس کا طویل ہونا ہی دلیلِ تکبر ہے، اب جھوٹی خارجی وقولی وضاحتوں کی چنداں ضرورت نہیں. (عارضة الأحوذي" (7/238)
علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "خلاصہ یہ ہے کہ کپڑا لٹکانے کا عمل لباس کو گھسیٹنے کا سبب بنتا ہے، اور لباس گھسیٹنے کا عمل تکبر کی طرف لے جاتا ہے، چاہے پہننے والے کی نیت تکبر کی نہ بھی ہو۔" (فتح الباري (10/264)
اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ازار کو گھسیٹنے سے بچو، کیونکہ ازار کا گھسیٹنا تکبر کی علامت ہے۔" (فتح الباري (10 / 264)
4. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ:
رسول اللہ ﷺ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا کہ: "آپ ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ تکبر کے ساتھ کرتے ہیں." اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بغیر تکبر کے کپڑا لٹکانا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جب بھی ان کا ازار ڈھیلا ہو جاتا، وہ اسے درست کرلیتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ آج کل إسبال ازار کی وکالت کرنے والے تو باضابطہ دراز قد پینٹ قصداً وعمداً خرید کر پہنتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے گنجائش ڈھونڈنے کی سعی لاحاصل کرتے ہیں، بلا قصد وعمد کے کبھی ایسا ہوجائے تو مجبوری کی یہ صورت کراہت تنزیہی کے زمرے میں آکر قابل عفو ہے جیساکہ فقہاء حنفیہ کا مذہب ہے؛ لیکن ٹخنہ سے نیچے ازار لٹکانے کا فیشن بنا لینا اس بابت سخت نبوی وعیدوں کے ہوتے ہوئے کسی بندہ مومن کے لئے قطعی جائز نہیں ہے، اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے۔ اس میں زندگی کے ہر گوشے کی تشفی بخش رہنمائی موجود ہے۔کسی بھی دوسرے مذہب اور تہذیب وتمدن سے کچھ لینے اور خوشہ چینی کی ضرورت نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں مسلمانوں سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی عام ہے کہ اسلامی عقائد واعمال اور احکام وتعلیمات کی صداقت وحقانیت پہ دل ودماغ بھی مطمئن ہو اور اعضاء وجوارح اور وضع قطع بھی عملی ثبوت پیش کریں۔ارشادات نبوی سے معارض کسی عرف وکلچر کی کوئی وقعت نہیں۔
"ما أسفل من الكعبين من الإزار، ففي النار" (جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا) کی توجیہ!
حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا بھی ممکن ہے کہ ازار لٹکانے والے کے کپڑے بھی دوزخ میں جائیں گے، جیساکہ ارشاد باری ہے: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) [الأنبياء: 98]
طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: "نبی اکرم ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنا ازار لٹکایا ہوا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:
"اے ابن عمر! جو کپڑا زمین کو چھوتا ہے، وہ آگ میں ہوگا۔ (”فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: "يَا ابْنَ عُمَرَ، كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَمِنَ الثِّيَابِ، فَفِي النَّارِ "مسند احمد 5831)
علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ دو طرح سے کی جا سکتی ہے:
1. یہ کہ ٹخنوں سے نیچے کا جو حصہ (پاؤں) ہوگا، وہ اس عمل کے بدلے میں سزا کے طور پر آگ میں ہوگا( تسمية الشيء باسم ما جاوره)
2. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اور وہ فعل جو اس نے کیا، وہ آگ کے اعمال میں سے شمار ہوگا، یعنی یہ ان اعمال میں شامل ہے جو اہلِ جہنم کے اعمال میں گنے جاتے ہیں۔ [معالم السنن (4/183) طبعة المكتبة العلمية]
نماز سے پہلے پائنچے اوپر کرنے کا اعلان؟
ٹخنہ سے نیچے کپڑے لٹکانا نماز کے اندر اور باہر ہر دو حالتوں میں مکروہ ہے. نماز کے اندر اس کی کراہت دو چند ہے. ابودائود کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتے (وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ 543)
اگرکسی کالباس ایسا ہوکہ بلا قصد ٹخنے ڈھک جاتے ہوں تو اسے کم ازکم نمازسے پہلے پائنچہ اوپر کرلینا چاہیے، یہ عمل وعیدِ "کفّ ثوب" (لاَ أکُفُّ شَعْراً وَلاَ ثَوْباً․ بخاری 816) میں شامل نہیں ہے. "کف ثوب" یہ ہے کہ نمازی دوران نماز آستین وغیرہ فولڈ کرے۔ (قوله كمشمر كم أو ذيل) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة (شامی 640/1)
اگر نماز شروع ہونے سے قبل اس کی ہدایت کی جاتی ہے تو یہ درست عمل ہے؛ تاکہ نماز کراہت تحریمی سے بچ جائے، جو فعل نماز سے باہر گناہ ہو ،نماز میں اس کاگناہ مزید بڑھ جاتا ہے۔
خلاصہ: إسبال ازار کی حرمت عام ہے، إسبال کا عمل بذات خود کبر وغرور کی دلیل ہے، اس ممانعت کی اصل حکمت یہ ہے کہ انسان تکبر سے بچ کر عاجزی اختیار کرے، مال و دولت کی نمائش سے اجتناب کرے، صفائی کا خیال رکھے، اور اسلامی تشخص کو اجاگر کرے۔ یہ ہدایت نہ صرف ظاہری عمل کی اصلاح کے لیے ہے بلکہ باطنی صفات کو بھی بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ عذر ومجبوری اور لاعلمی کی صورتیں مستثنی ہیں، فقہاء حنفیہ کے اقوال کا محمل یہی ہے، لیکن قصد وارادہ کے ساتھ لمبا ازار وپینٹ پہننا اور اس کی ترویج واشاعت کرنا ناجائز اور قابل لعنت عمل ہے، جب اس عمل کو ہی دلیل تکبر بنادیا گیا تو اب نیتوں کی توجیہات ناقابل التفات واعتبار ہونگی، نماز کے اندر وباہر ہر جگہ یہ طریقہ ناجائز ہے، ازار اور کپڑے کے لیے مستحب وبہتر یہ ہے کہ وہ نصف پنڈلی تک ہو، بغیر کسی کراہت کے جائز یہ بھی ہے کہ ٹخنوں تک ہو؛ لیکن جو ٹخنوں سے نیچے ہو، وہ ممنوع وناجائز ہے، پھر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ازراہ فیشن و عُجب وتکبر کے ہو تو یہ سختی سے حرام وگناہ کبیرہ ہے، اور اگر بغیر تکبر کے لاعلمی میں کبھی کبھار ہوجائے یا کسی مجبوری کے تحت ہوجائے تو یہ مکروہِ تنزیہی (ناپسندیدہ) ہے، چونکہ ٹخنہ ڈھک کے نماز پڑھنا مزید سنگین اور نماز مسترد کردیے جانے کا سبب ہے؛ اس لئے نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے، اگر کوئی اس جانب توجہ مبذول کروائے (اعلان کرے) تو یہ شرعاً جائز ہے اس پر عمل کیا جائے اور کم از کم وقتی طور پہ فولڈ کرکے نماز پڑھ لے، فولڈ کا یہ عمل ممنوع ہیئت (کفّ ثوف) میں داخل نہیں ہے، جو لوگ اس پہ منفی پراپیگنڈہ کرتے ہیں وہ ادلہ شرعیہ کے درست تطبیق وتجزیہ سے قاصر ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب
مركز البحوث الإسلامية العالمي ( #ایس_اے_ساگر)
(منگل6؍ رجب المرجب 1446ھ 7؍ جنوری 2025ء)
https://saagartimes.blogspot.com/2025/01/blog-post_7.html